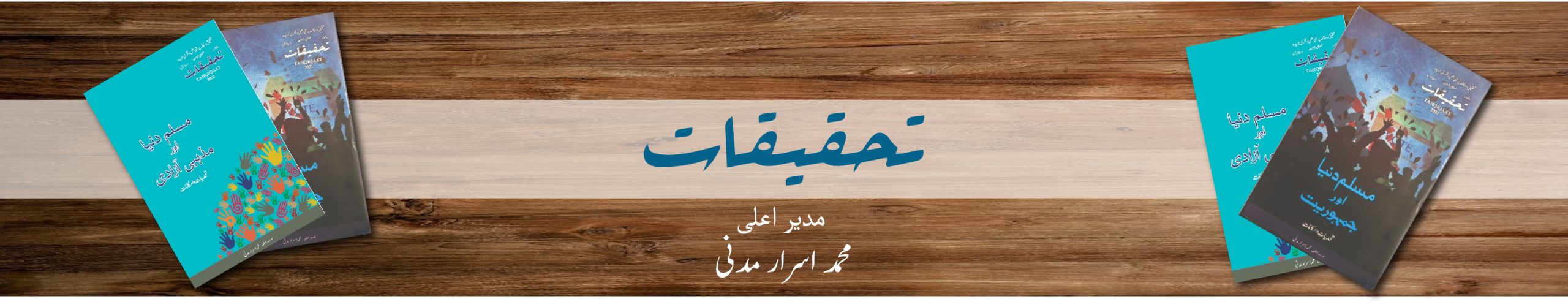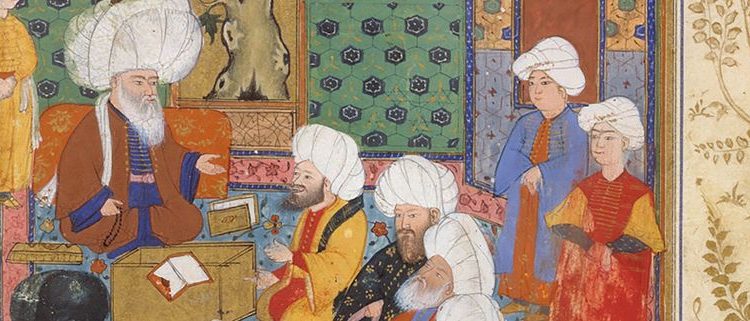یہ مضمون تحقیقات کے خصوصی شمارے ’مسلم دنیا اور دستوری بحران‘ (2024ء) میں شائع ہوا ہے۔
19ویں صدی کے دوران مسلم دنیا میں مغربی استعمار کا اثر بڑھا۔ یورپی طاقتوں کی جانب سے مسلم ریاستوں کی زمینوں پر قبضے اور سیاسی، اقتصادی اثر و رسوخ نے مسلم حکمرانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ان کے سیاسی ڈھانچوں کو جدید ضروریات کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم دنیا میں جدید ریاستی ڈھانچے اور آئینی دستاویزات کی ضرورت کا احساس بڑھا۔ یہ بیداری صرف اشرافیہ تک محدود نہیں تھی بلکہ عوام میں بھی اس کی گونج سنائی دی۔ان مسلم ممالک نے مغربی جمہوریت کی بنیادوں پر اپنے آئین کی تشکیل کی، ساتھ ساتھ اسلامی اقدار اور روایات کو بھی برقرار رکھنے کی کوشش کی۔
ابتدا میں مغربی خیالات اور آئینی حکومت کے نظام پر بعض مذہبی حلقوں کا ردعمل منفی تھا۔ بعض علماء نے مغربی اصولوں اور سیاسی خیالات کو اسلام سے متصادم سمجھا اور انہیں اسلامی اقدارکے خلاف قرار دیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ "شورٰی” (consultation) اور "بیعت” (pledge of allegiance) جیسے روایتی اصولوں کو ترک کرنا غیر اسلامی ہے۔ ان کے مطابق، اسلامی ریاست کا اصل قانون شریعت ہے، اور اس میں کسی قسم کی تخفیف یا اس کے مقابلے میں دوسرے قوانین کا نفاذ نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پہ وہ آئینی اصلاحات کی حمایت اس صورت میں کرتے تھے جب ان میں شریعت کی بالادستی اور اسلامی قوانین کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے۔ تاہم، علماء کے دوسرے طبقے نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جدید معاشی اور سماجی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حکومتوں کو بعض اصلاحات کرنا ضروری ہیں، اور آئین کی موجودگی میں ان اصلاحات کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔
آئین کی تشکیل میں ہر ملک نے اپنے مخصوص چیلنجز اور حالات کے مطابق قدم اٹھایا۔ یہاں ہم مسلم دنیا کے پہلے ایسے چند ممالک کا جائزہ لیں گے جنہوں نے دستور وضع کیا۔ مسلم دنیا میں آئینی اصلاحات کی تحریک کا آغاز مختلف ممالک میں مختلف انداز میں ہوا، تاہم عثمانی سلطنت اور تیونس کی مثالیں اس تحریک کا نقطہ آغاز تھیں۔
عثمانی سلطنت اور تیونس میں آئینی اصلاحات کی تحریکوں کا ایک بڑا محرک عوامی بیداری تھی۔ مغربی تعلیم، پریس، اور تجارتی تعلقات نے مسلم عوام کو آئینی اصلاحات کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا۔ ان اصلاحات کا مقصد صرف حکومتی ڈھانچے کی تبدیلی نہیں تھا، بلکہ عوامی حقوق کے تحفظ، حکومت کے اختیارات کی تقسیم، اور شفافیت کو یقینی بنانا تھا۔
تیونس – 1861
تیونس میں 1861 میں مسلم دنیا کاپہلا آئین متعارف کرایا گیا تھا جو اصل میں مغربی دنیا سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا۔اُس وقت تیونس کے حکمران احمد باشا نے اس کی تشکیل کا اعلان کیا تھا، جسے (Code of Fundamental Laws) کہا گیا۔
اس آئین کا مقصد ملک کے حکومتی ڈھانچے کو جدید بنانا تھا اور سلطنت کی قدیم بادشاہت کو آئینی شکل میں ڈھالنا تھا۔ اس آئین میں شریعت کوبھی اہمیت دی گئی تھی۔ آئین میں حکومت کی شکل، اختیارات کا تقسیم اور شہری حقوق کی وضاحت کی گئی تھی۔ اس میں ایک آئینی پارلیمنٹ کی تشکیل کی تجویز بھی دی گئی تھی، جسے عوام کی نمائندگی ملنی تھی۔ تاہم، اس آئین کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ اسلامی شریعت کے اصولوں کو مکمل طور پر نظرانداز نہ کیا جائے اور انہیں حکومت کی بنیاد بنانے کی کوشش کی جائے۔اس دستور کی تشکیل کے بعد بھی تیونس میں مختلف سیاسی اور سماجی گروپوں کے درمیان اس بات پر اختلافات قائم رہے کہ آیا یہ آئین اسلامی شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔تیونس میں اُس وقت آئین میں ذکر کردہ مغربی جمہوریت کے اصولوں کا عملی طور پر نفاذ کرنا بھی چیلنج تھا، کیونکہ تیونس میں عوامی سیاسی شعور اور جمہوری اداروں کا فقدان تھا۔ جمہوری اداروں کے قیام کے لیے عوامی حمایت حاصل کرنا ایک مشکل امر تھا، اور ملک کے اندرونی معاملات میں اصلاحات کے لیے اچھی خاصی مزاحمت موجود تھی جس کا فائدہ بادشاہت کو ہوا۔ اس کے علاوہ، حکومتی ڈھانچوں میں عملی تبدیلی کے لیے طاقتور طبقات کی رضامندی کی بھی ضرورت تھی، جس میں فوج اور جاگیردار طبقہ شامل تھا،جنہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔
تیونس کے 1861 کے آئین میں پانچ اہم ترین شقیں درج ذیل تھیں:
(1)بادشاہت کے محدود اختیارات
اس آئین کے ذریعے بادشاہ کے اختیارات کو محدود کیاگیا، جس سے دستوری بادشاہت (Constitutional Monarchy) سامنے آئی۔ بادشاہ کے فیصلے حکومتی اداروں اور آئینی اصولوں کے تابع کر دیے گئے، اور حکومتی امور میں بادشاہ کو مکمل آزادی حاصل نہیں تھی۔
(۲)وزارت عظمی اور کابینہ کی تشکیل
آئین کے تحت وزیرِ اعظم کا عہدہ وضع کیا گیا، جس کی ذمہ داری حکومتی معاملات کی نگرانی تھی۔ کابینہ اور دیگر وزراء کو بھی آئینی حیثیت دی گئی، جس سے حکومتی ڈھانچے میں ایک منظم طریقۂ کار قائم ہوا۔
(۳)شریعت اور جدید قوانین کا امتزاج
آئین میں شریعت کے قوانین کو اہمیت دی گئی، اور تیونس کی قانونی روایات کو بھی برقرار رکھا گیا۔ لیکن یہ مکمل طور پر اسلامی قوانین پر مبنی نہیں تھا بلکہ اس میں مغربی قانونی اصولوں کا بھی امتزاج تھا۔
(۴)شہری حقوق اور انصاف کی فراہمی
آئین میں پہلی بار شہریوں کے حقوق اور انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اس میں خاص طور پر جائداد کے حقوق، عدلیہ کا معیار، اور عوامی معاملات میں شفافیت کو اہمیت دی گئی، جس سے تیونس میں انصاف کے نظام کی بنیادیں مضبوط ہوئیں۔
(۵)مشاورتی اسمبلی کا قیام
آئین کے مطابق ایک مشاورتی اسمبلی (Consultative Assembly) یا پارلیمنٹ کا قیام عمل میں آیا، جس کے اراکین کو ملک کی نمائندگی کی ذمہ داری دی گئی۔ اس اسمبلی کا مقصد عوامی مفادات کو حکومتی پالیسیوں میں شامل کرنا اور قوانین کی تشکیل میں عوامی نمائندوں کی شمولیت کو یقینی بنانا تھا۔
عثمانی سلطنت (ترکی)۔1876
عثمانی سلطنت کا پہلا آئین1876 میں نافذ کیا گیا تھا۔ یہ آئین سلطنت کی پہلی تحریری قانونی دستاویز تھی، جو مشروط بادشاہت کے اصولوں پر مبنی تھی۔ سلطان عبدالحمید دوم کے عہد میں یہ آئین متعارف کرایا گیا، جس کا مقصد سلطنت عثمانیہ کو جدید بنانا تھا۔ اس آئین میں سلطان کے اختیارات کو محدود کردیا گیا تھا۔ بعد میں 1908 میں آئینی انقلاب کے دوران اس دستور کو مزید مؤثر بنایاگیا۔عثمانی سلطنت میں اسلامی شریعت اور مغربی جمہوری اصولوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ اس آئین نے سلطنت میں ایک قانونی نظام متعارف کرایا تھا، لیکن مغربی ماڈل کو اپنانے کی وجہ سے بہت سے علما نے اسے غیر اسلامی قرار دیا۔ مغربی طاقتیں خاص طور پر برطانیہ اور فرانس عثمانی سلطنت میں اپنے اثرات بڑھانے کے لیے آئینی اصلاحات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتی تھیں، جس کی وجہ سے مقامی سطح پر بھی ایک تنازعہ پیدا ہوا۔
عثمانی عہد میں سب سے پہلے 1839 میں "تنظیمات” (Tanzimat) کی تحریک کا آغاز ہوا۔ یہ تحریک عثمانی سلطنت کے حکمرانوں کی جانب سے آئینی اصلاحات کی ایک کوشش تھی، جس کا مقصد ریاستی اداروں میں اصلاحات اور غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کو تسلیم کرنا تھا۔1876 کا عثمانی آئین ، جو ’ بنیادی قانون‘ (قانونِ اساسی) کے نام سے جانا جاتا ہے، سلطنت کی پہلی تحریری قانونی دستاویز تھی اور اس کا مقصد سلطنت عثمانیہ میں جدید اصلاحات لانا تھا۔ اس آئین کے نفاذ کا بنیادی مقصد سلطنت کو داخلی طور پر مستحکم بنانا اور اسے مغربی جمہوریت کے اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنا تھا، تاہم اس میں اسلامی شریعت کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا تھا۔ یہ آئین سلطنت کے مرکزی اداروں میں اصلاحات اور مشروط حکمرانی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔
عثمانی سلطنت میں پہلے آئین کی ضرورت اس وقت شدت سے محسوس کی گئی جب سلطنت ایک طرف مغربی دنیا سے صنعتی اور علمی میدان میں پیچھے جا رہی تھی، اور دوسری طرف سلطنت کو اندرونی مسائل جیسے کہ بڑھتی ہوئی کرپشن، عسکری ناکامیاں، اور علیحدگی پسند تحریکوں کا سامنا تھا۔ اس پس منظر میں سلطان عبدالحمید دوم کی حکومت میں آئین بنانے کی کوششیں شروع ہوئیں۔اس آئین کے تحت ایک پارلیمنٹ کا قیام شامل تھا جس کے ذریعے عوامی نمائندگی کو یقینی بنایا گیا تھا۔ اس آئین نے سلطان کے اختیارات کو محدود کر دیا تھا۔ اس میں شریعت کے اصولوں کو نظرانداز کیے بغیر، ریاستی نظام میں جدید اصلاحات کی گئیں۔ آئین کے اندر سلطنت میں تمام افراد کے مساوی حقوق کی ضمانت دی گئی تھی، اور عوامی آزادی، اظہار کی آزادی، اور تنظیم بنانے کی آزادی جیسے بنیادی حقوق فراہم کیے گئے تھے۔
اس آئین کوکچھ علماء نے "غیر اسلامی” قرار دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مغربی جمہوری ماڈل اسلامی اصولوں کے خلاف تھا۔ خاص طور پر، آئین میں بادشاہ کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش ان کے مطابق بالکل صحیح نہیں تھی، کیونکہ یہ ان کے مطابق اسلامی شریعت کے تحت حکمرانی کے اصولوں کے خلاف عمل تھا۔اسلامی حکمرانی میں "خلافت” یا "امارت” کا تصور ہے جو ایک مضبوط مرکزی قیادت کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔
اگرچہ یہ آئین 1876 میں نافذ کیا گیا تھا، لیکن اسے مکمل طور پر فعال نہ کیا جا سکا۔ اس کی ایک بڑی وجہ سلطنت عثمانیہ کے مختلف حصوں میں اس کی حمایت نہ ہونا تھی، اور بادشاہ کی جانب سے اس آئین پر عمل نہ کرنا بھی ایک سبب تھا۔ اس لیے، 1908 میں "آئینی انقلاب” (The Young Turk Revolution) کے دوران، اس آئین کو فعال اور مؤثربنا دیا گیا۔ یہ انقلاب ان ترک قوم پرستوں کی تحریک کا نتیجہ تھا جنہوں نے "جمعیت اتحاد و ترقی” (Committee of Union and Progress) کے زیر اہتمام عثمانی سلطنت میں جمہوری اصلاحات لانے کی کوشش کی تھی۔1908 کے انقلاب کے نتیجے میں، عثمانی پارلیمنٹ کا کردار مزید مضبوط ہوا، اور عوام کے حقوق کے تحفظ کی طرف ایک اہم قدم بڑھایا گیا۔ اس انقلاب کے بعد سلطنت عثمانیہ میں سیاسی اور سماجی تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں۔
عثمانی سلطنت کے اس آئین کی پانچ اہم ترین خصوصیات یہ تھیں:
(۱)سلطان کے اختیارات کی تحدید
اس آئین نے سلطان کے اختیارات کو محدود کیا۔ اس کے تحت ریاستی فیصلوں میں سلطان کے اختیارات کو آئینی اصولوں کے تابع کر دیا گیا۔
(۲)مذہبی اقلیتوں کے حقوق
آئین میں غیر مسلم اقلیتوں، جیسے مسیحیوں اور یہودیوں، کے حقوق کو تسلیم کیا گیا اور انہیں عثمانی سلطنت کے شہریوں کے مساوی حقوق دیے گئے۔ اس شق کا مقصد سلطنت میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا تھا، تاکہ سلطنت کے اندر اتحاد اور ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے۔
(۳)آزادانہ پریس کا حق
آئین میں پہلی بار آزادیِ صحافت کو تسلیم کیا گیا، جس کے تحت سلطنت کے اندر اخبارات اور رسائل کو حکومتی نگرانی کے بغیر کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ شق اس بات کا اظہار تھی کہ حکومت شہریوں کو معلومات تک رسائی کے حق کو تسلیم کرتی ہے اور حکومت کی پالیسیوں پر عوامی مباحثے کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ تاہم، بعد میں یہ آزادی مختلف وجوہات کی بنا پر محدود کی گئی۔
(۴)شورائیت اور پارلیمنٹ کا قیام
آئین میں پارلیمنٹ کے دو ایوانوں پر مشتمل ایک نظام کا قیام عمل میں لایا گیا: مجلسِ شوریٰ (Senate) اور مجلسِ نمائندگان (Chamber of Deputies)۔ مجلسِ نمائندگان کے اراکین کا انتخاب عوامی نمائندگی کی بنیاد پر ہونا تھا، جبکہ مجلسِ شوریٰ کے اراکین کا تقرر سلطان کرتا تھا۔
(۵)وزارتوں اور سرکاری اداروں کی تشکیل
آئین میں مختلف وزارتوں کا قیام اور ان کے اختیارات کی وضاحت کی گئی، جس کے تحت سلطنت کے مختلف انتظامی شعبوں کو منظم کیا گیا۔ یہ دفاتر، جیسے کہ وزارتِ عدلیہ، وزارتِ مالیات، اور وزارتِ خارجہ کا قیام۔
ایران ۔1906
ایران میں پہلی آئینی تحریک 1906 میں شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں ایران کا آئین 1906 میں منظور کیا گیا۔یہ آئین "مجد الشریعت” کے اصولوں پر مبنی تھا اور اسے ملکی سیاست میں اسلامی کردار کا مظہر سمجھا جاتا تھا۔ اس آئینی تحریک کا اصل مقصد شاہی حکومت کی مطلق العنانیت کو محدود کرنا اور ایک آئینی بادشاہت قائم کرنا تھا۔ اس تحریک کا آغاز سماجی اور سیاسی اصلاحات کی ضرورت کی وجہ سے ہوا، کیونکہ عوام میں شاہی حکومت کے جابرانہ طریقوں کے خلاف نارضگی بڑھ رہی تھی۔ ایران میں شاہ کی حکومت کے خلاف عوامی مزاحمت پہلے سے موجودتھی،پھر اس میں علماء کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہو گئی۔ ایرانی عوام اور علماء نے مل کر آئینی تحریک شروع کی، جس کے نتیجے میں 1906 میں ایران کا آئین منظور کیا گیا۔اس مرحلے میں شاہی حکومت اور علماء کے درمیان مسلسل تنازعہ رہا، جس میں بے پناہ ریاستی طاقت اور اسلامی اقدار کے تحفظ کے درمیان توازن قائم کرنا مشکل تھا۔ بعد میں 1979 کے اسلامی انقلاب کے دوران یہ آئین مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا۔اس آئین کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ اس میں اسلامی شریعت کو آئین کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ آئین میں یہ طے کیا گیا تھا کہ تمام قوانین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں گے، اور شریعت کے مطابق عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔آئین میں اسلامی عدالتوں کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا تھا۔اگرچہ ایران کا آئین 1906 میں منظور کیا گیا تھا، لیکن اس کے نفاذ کے دوران کئی مشکلات پیش آئیں۔ آئین میں متعین اصولوں کو عملی طور پر نافذ کرنا آسان نہیں تھا۔شاہی حکومت نے آئین کے تحت اپنی طاقت کو محدود کرنے کے لیے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے۔ پھر 1979 میں اسلامی انقلاب کے دوران ایران میں ایک نیا آئینی ڈھانچہ تشکیل دیا گیا، جس میں اسلامی جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس انقلاب نے شاہی حکومت کو ختم کیا اور ایران کو ایک اسلامی جمہوری ریاست میں تبدیل کر دیا۔
ایران کے 1906 کے آئین کی پانچ اہم ترین شقیں یہ تھیں:
(۱)قانون سازی میں مذہبی علماء کا کردار
آئین کی ایک اہم شق یہ تھی کہ قانون سازی میں اسلامی شریعت کا احترام کیا جائے گا، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے علماء کو قومی مجلس کے قوانین کی منظوری میں کردار دیا گیا۔ اس کے تحت علماء کو مجلس کی قانون سازی کے جائزے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونے کے بارے میں حتمی رائے دینے کا اختیار حاصل تھا۔
(۲)مجلس شورائے ملی کی خود مختاری
آئین میں مجلسِ شورائے ملی (قومی اسمبلی) کی خود مختاری کو یقینی بنایا گیا، جو اس وقت کے سیاسی نظام میں ایک نیا قدم تھا۔ مجلس کو مالیات، ٹیکس، اور حکومتی پالیسیوں پر فیصلہ سازی کا اختیار دیا گیا۔ اس سے ایرانی عوام کو پہلی بار حکومتی معاملات میں باقاعدہ نمائندگی ملی۔
(۳)قضاء کا نظام اور عدالتی اصلاحات
1906کے آئین نے ایک عدالتی نظام متعارف کرایا جس میں اسلامی شریعت کی بنیاد پر قضاء کا نظام قائم کیا گیا۔ اس میں روایتی اسلامی عدلیہ کو برقرار رکھا گیا اور اس کے تحت قضا کے امور کو شریعت کی روشنی میں چلایا گیا۔ تاہم، آئین میں عدلیہ کی تنظیم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔
(۴)مقامی حکومتوں کو اختیارات کی فراہمی
آئین میں مقامی حکومتوں کو اختیارات کی فراہمی پر بھی زور دیا گیا، جس کے تحت ایران کے مختلف علاقوں میں مقامی حکومتیں خود مختار طور پر انتظامی معاملات چلا سکتی تھیں۔ اس شق کا مقصد علاقائی مسائل کے حل کے لیے مقامی سطح پر فیصلہ سازی کو فروغ دینا تھا۔
(۵)وزراء کے احتساب کا اصول
آئین میں وزراء کے احتساب کا اصول شامل کیا گیا، جس کے تحت وزیر اعظم اور دیگر وزراء کو پارلیمنٹ کے سامنے جوابدہ بنایا گیا۔ اس سے حکومت کے مختلف شعبوں میں شفافیت اور احتساب کا نظام متعارف کرایا گیا، تاکہ وزراء کی کارکردگی پر نظر رکھی جا سکے اور وہ عوامی مفاد کے مطابق کام کریں۔
مصر۔ 1923
مصر کا آئین 1923 میں تیار کیا گیا، جس کے تحت ملک میں آئینی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ یہ آئین مصر میں جمہوری نظام کے آغاز کا پیش خیمہ تھا، اور اس میں اسلامی اصولوں کو بھی اہمیت دی گئی تھی ۔ اس آئین میں پہلی بار مصر میں مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ کے الگ الگ اختیارات کی وضاحت کی گئی۔1952 میں فوجی انقلاب کے بعد اس آئین کو منسوخ کر دیا گیا اور مصر میں آئینی اصلاحات کی ایک نئی لہر شروع ہوئی۔
1923کےاس آئین میں ریاست کے تمام قوانین کو اسلامی قوانین کے مطابق ترتیب دینے کا عہد کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی اسے مغربی جمہوری اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔1952 میں مصر میں فوجی انقلاب آیا تویہ آئین منسوخ کر دیا گیا۔ اس انقلاب کی قیادت جمال عبدالناصر نے کی تھی، اور اس کا مقصد مصر میں سیاسی نظام کی جڑوں کو تبدیل کرنا تھا۔ جمال عبدالناصر نے اس انقلاب کے بعد ملک میں ایک نیا آئین بنانے کی کوشش کی، جس میں زیادہ تر طاقت فوج کے ہاتھ میں آ گئی۔فوجی انقلاب کے بعد، مصر میں آئینی اصلاحات کی ایک نئی لہر شروع ہوئی، جس میں پہلے سے موجود آئینی اور قانونی ڈھانچے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ ناصر کی حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا کہ آئین میں کسی قسم کی اسلامی شریعت کی چھاپ نہ ہو، اور اس کے متبادل ایک سوشلسٹ نظام قائم کیا جائے۔ ناصر کی حکومت میں سیکولرزم کی جانب ایک واضح جھکاؤ تھا۔
مصر میں 1923 کے دستورکی تشکیل کے دوران علماء کا ردعمل ملا جلا تھا۔ کچھ علماء نے آئین کی حمایت کی کیونکہ اس میں اسلامی احکام کا احترام کیا گیا تھا، تاہم بعض علماء کا خیال تھا کہ مغربی جمہوریت کا نفاذ اسلامی معاشرتی نظام کے خلاف ہے۔ ان علماء کا ماننا تھا کہ اسلامی ریاست کو مغربی جمہوریت کے اصولوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کی حقیقی اقدار کے مطابق نہیں ہیں۔تاہم، 1952 کے انقلاب بعد جب جمال عبدالناصر کی حکومت نے سیکولر اقدار کو اپنانا شروع کیا، تو علماء کی ایک بڑی تعداد نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اُس وقت مصر میں اسلامی حلقوں میں بڑے پیمانے پر ناراضگی پیدا ہوئی، کیونکہ انہیں احساس ہوا کہ اسلامی ریاست کی بنیاد پر جو نظام پہلے پیش کیا گیا تھا، اسے اب منسوخ کر کے ایک سیکولر نظام قائم کیا جا رہا ہے۔
1923 میں مصر کے آئین کی چند اہم شقیں یہ تھیں:
(۱)وزیر اعظم کی تقرری
آئین کے تحت وزیر اعظم کو بادشاہ کی منظوری سے مقرر کیا جاتا تھا، اور وہ کابینہ کا سربراہ ہوتا تھا۔ وزیر اعظم کے پاس حکومتی امور چلانے اور کابینہ تشکیل دینے کا اختیار تھا۔
(۲)مقننہ، عدلیہ، اور انتظامیہ کی علیحدگی
آئین میں قانون ساز، عدلیہ، اور انتظامی شعبوں کو الگ الگ حیثیت دی گئی۔ اس علیحدگی کا مقصد یہ تھا کہ ہر ادارہ اپنے اختیارات میں خود مختار رہے اور کسی دوسرے ادارے کی حدود میں مداخلت نہ کرے۔
(۳)ووٹ ڈالنے کا حق
آئین نے بالغ مردوں کو انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق دیا، جو ملک میں عوامی نمائندوں کے انتخاب کے ذریعے جمہوری عمل کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم قدم تھا۔
(۴)پارلیمنٹ کی تشکیل
اس آئین نے دو ایوانوں پر مشتمل پارلیمنٹ تشکیل دی: ایوانِ نمائندگان اور ایوانِ شیوخ۔ یہ پارلیمنٹ قانون سازی اور حکومتی معاملات پر نظر رکھنے کی ذمہ دار تھی۔
(۵)عوامی نمائندگی اور آئین میں ترمیم کا حق
آئین نے پارلیمنٹ کو یہ اختیار دیا کہ وہ عوام کی خواہشات کے مطابق آئین میں ترمیم کر سکے، تاہم اس کے لیے سخت قواعد و ضوابط مقرر کیے گئے تھے تاکہ آئین میں غیر ضروری تبدیلیاں نہ کی جا سکیں۔
لبنان ۔1926
لبنان کا آئین 1926 میں فرانسیسی منصوبے کے تحت تشکیل دیا گیا، اور یہ ایک سیکولر آئین تھا۔ لبنان کے آئین میں تمام اقلیتی گروہوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا تھا، اور اس میں کوئی خاص اسلامی شریعت کی دفعات نہیں تھیں۔لبنان میں آئینی جدوجہد کا سب سے بڑا مقصد مختلف مذہبی کمیونٹیوں کے درمیان توازن قائم کرنا تھا۔ لبنان کا آئین مختلف مذہبی گروہوں کے درمیان سیاسی اقتدار کی تقسیم کو واضح کرتا ہے۔چونکہ یہ فرانسیسی عملداری کے تحت تشکیل دیا گیا تھا، اس کی وجہ سے اسے خطے کے دیگر مسلم ممالک کے آئین سے ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ یہ آئین بنیادی طور پر ایک سیکولر آئین تھا جس میں ملک کے تمام شہریوں کو مذہبی بنیاد پر برابر حقوق دینے کی کوشش کی گئی۔اس آئین نے مسیحی، مسلمان، اور دیگر مذہبی کمیونٹیز کو سیاسی اور سماجی حقوق فراہم کیے اور ہر کمیونٹی کو پارلیمان میں نمائندگی کا حق دیا۔ مثال کے طور پر، صدر کا عہدہ مسیحی مراونی، وزیراعظم کا عہدہ سنی مسلمان، اور پارلیمنٹ کے اسپیکر کا عہدہ شیعہ مسلمان کے لیے مخصوص کیا گیا۔ اس طرح مختلف مذہبی کمیونٹیز کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ فرقہ وارانہ تقسیم اور سیاسی عدم استحکام لبنان کی سیاسی تاریخ میں اہم مسئلہ رہا ہے۔اگرچہ آئینی ڈھانچے میں طاقت کی تقسیم تو کی گئی، لیکن یہ مختلف گروہوں کے درمیان کشیدگی کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکا۔
1926 میں لبنان کے آئین کی چند اہم شقیں یہ تھیں:
(۱)مذہبی تقسیم پر مبنی نظام حکومت
لبنان کے آئین کی ایک منفرد شق یہ تھی کہ ملک کا نظام حکومت مذہبی بنیادوں پر قائم کیا گیا۔ صدر مسیحی، وزیرِ اعظم سنی مسلم، اور اسپیکر شیعہ مسلم ہوگا، تاکہ مختلف برادریوں کے درمیان توازن برقرار رکھا جا سکے۔
(۲)آزاد اور خود مختار ریاست کا قیام
آئین میں لبنان کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کیا گیا، حالانکہ فرانس کی نگرانی میں یہ آزادی محدود تھی۔
(۳)فرانس کے ساتھ خصوصی تعلقات
اگرچہ لبنان کو ایک خود مختار ریاست قرار دیا گیا تھا، لیکن آئین میں فرانس کے ساتھ خصوصی تعلقات کی شرط بھی شامل تھی، جس کے تحت فرانس لبنان کی خارجہ پالیسی اور سیکورٹی امور میں اثر و رسوخ رکھتا تھا۔
(۴)آزادیِ مذہب
آئین نے شہریوں کو مذہبی آزادی دی، اور ہر فرد کو اپنی مذہبی شناخت کو برقرار رکھنے اور اس کی پیروی کرنے کا حق دیا۔
(۵)آئینی عدالت کا قیام
لبنان کے آئین میں ایک آئینی عدالت کے قیام کی شق شامل تھی جس کا مقصد آئین کی حفاظت اور اس کی خلاف ورزیوں کو روکنا تھا۔ اس عدالت کا کردار آئینی قوانین کی تشریح کرنا اور ان پر عمل درآمد کی نگرانی کرنا تھا۔ ایسے ہی حکومت کے اقدامات کو آئینی حدود کے اندر رکھنا اور کسی بھی غیر آئینی اقدام کو روکنا بھی ہدف تھا۔
اُردن ۔1946
اُردن میں 1946 میں آئین کی پہلی دفعہ تشکیل کی گئی، جس میں اسلام کو ریاستی مذہب قرار دیا گیا تھا۔ اسے شاہ عبداللہ اول کے دور حکومت میں وضع کیا گیا تھا۔ یہ ملک میں ایک جمہوری اقدار کو متعارف کرانے کی پہلی کوشش تھی۔اس آئین میں شاہی نظام کو برقرار رکھا گیا اور سیاسی نظام میں اصلاحات کی کوشش کی گئی تھی۔آئین میں اسلامی اقدار کو ریاستی نظام کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن مکمل طور پر شریعت کو نافذ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ اس میں پارلیمنٹ، مقننہ، اور انتظامیہ کے اختیارات کو واضح کیا گیا۔دراصل اسلامی اقدار کو شامل کرنے کے نام پر شاہ عبداللہ اول نے آئین کے ذریعے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسی لیےشاہی حکومت کو آئین میں مرکزی حیثیت دی گئی۔ دستور میں اسلامی اقدار کونظری حوالے سے تو اہمیت دی گئی تھی، لیکن اس پر عمل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی تھی۔
اُردن کے اس آئین کی چند اہم ترین شقیں یہ تھیں:
(۱)ریاست کا دین اسلام
آئین میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا تھا کہ اردن کا ریاستی مذہب اسلام ہے، اور اس کی تمام قانونی اور دستوری بنیادیں اسلامی اقدار پر استوار ہیں۔
(۲)سیاسی جماعتوں پر پابندیاں
آئین میں کسی خاص سیاسی جماعت کے قیام پر پابندی نہیں تھی، لیکن عملاً سیاسی جماعتوں کا کردار محدود رہا اور شاہی حکمت عملی کے مطابق سیاست کی جڑیں زیادہ تر پارلیمنٹ تک محدود رہیں۔
(۳)پارلیمنٹ کے دو ایوانوں کی تشکیل
آئین میں پارلیمنٹ کے دو ایوانوں کی تشکیل کا ذکر کیا گیا تھا: ایوانِ نمائندگان اور ایوانِ مشیران۔ دونوں ایوانوں کو قانون سازی میں حصہ لینے کی اجازت تھی، تاہم ایوانِ مشیران میں شاہی نمائندوں کی اکثریت تھی۔
(۴)عوامی انتخابات
آئین میں عوامی انتخابات کے ذریعے پارلیمنٹ کے اراکین کا انتخاب کرنے کا نظام وضع کیا گیا تھا۔ تاہم، انتخابات میں حکومتی کنٹرول اور شاہی اثر و رسوخ نمایاں تھا۔
(۵)شاہی فرمان کی اہمیت
آئین میں یہ وضاحت کی گئی تھی کہ بادشاہ کا فرمان تمام حکومتی فیصلوں میں اہمیت رکھتا ہے، اور شاہی فرمان کے بغیر کسی بھی اہم قانونی یا آئینی تبدیلی کا نفاذ ممکن نہیں تھا۔