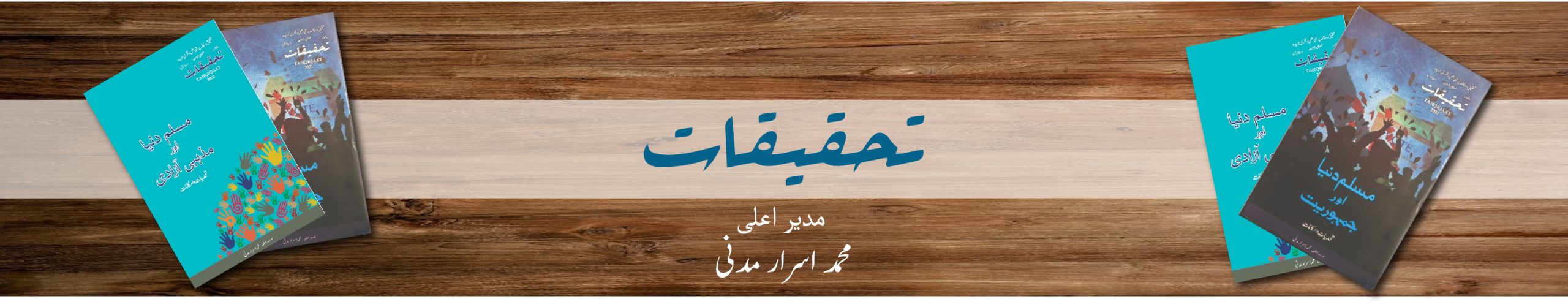افغان جہاد اور اسلامی دستور
یہ مضمون افغان نژاد مفکر شمشاد پسارلے کی کتاب The Constitutional Imagination of the Mujahidin: A History and Translation of T anslation of Two Constitutions Proposed b opposed by Afghan Islamist ghan Islamist Militias in the 1990s. کے ایک باب کا خلاصہ ہے، جو تحقیقات کے خصوصی شمارے ’مسلم دنیا اور دستوری بحران‘ (2024ء) میں شائع ہوا ہے۔ شمشاد پسارلے شکاگو یونیورسٹی امریکا میں مدرس ہیں۔
1979 سے 1992 تک جاری رہنے والے افغان جہاد نے، جو سوویت یونین کی جارحیت اور اس کے قائم کردہ حکومت کے خلاف شروع ہوا تھا، افغانستان میں ایک اسلامی معاشرے کے قیام کے تصور کو تقویت دی۔ اس دوران عام مسلمان یا تو روایتی علماء سے رہنمائی لیتے رہے یا جدید فکر کے حامل نظریات کے پیروکار بنے، لیکن زیادہ تر افراد حکومتوں پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ حکومتیں "جدیدیت” کے نام پر اوپر سے مسلط کی گئی ایسی پالیسیاں نافذ کر رہی تھیں جو نہ صرف اسلامی اصولوں سے ہم آہنگ نہیں تھیں بلکہ عوام کے مذہبی جذبات کا بھی خیال نہیں رکھتی تھیں۔
1970 کی دہائی میں کئی سیاسی انقلابات نے افغان بادشاہت کا خاتمہ کیا اور قوم پرست آمرانہ حکومتوں کے قیام کی راہ ہموار کی۔ ان حکومتوں نے سماجی اور معاشی اصلاحات کے نام پر سخت گیر پالیسیاں نافذ کیں، جس کے خلاف عوامی مزاحمت بڑھتی گئی۔ بالآخر افغان کمیونسٹ پارٹی کی حکومت نے اس بڑھتی ہوئی مزاحمت کو کچلنے کے لیے سوویت یونین کو ملک میں مداخلت کی دعوت دی۔
سوویت جارحیت اور کمیونسٹ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف مزاحمت میں اسلامی نظریات رکھنے والے گروہ پیش پیش تھے۔ سنی اور شیعہ اسلام پسند جماعتوں نے عسکری تنظیمیں تشکیل دیں اور سوویت حمایت یافتہ حکومت کے خلاف ایک اتحاد قائم کیا۔ لیکن جب یہ اتحاد سوویت افواج کو پسپا کرنے اور افغان حکومت کو ختم کرنے میں کامیاب ہوا تو اندرونی اختلافات نے اسے تقسیم کر دیا۔
یہ اختلافات اس بات پر تھے کہ ایک اسلامی ریاست کیسی ہونی چاہیے، اس کا نظام ِحکومت کیا ہو اور معاشرے پر کون سے قوانین نافذ کیے جائیں۔ انہی بحث و مباحثوں کے نتیجے میں مختلف اسلامی آئینی خاکے تیار کیے گئے، جن میں ہر خاکہ ایک الگ تصور کی نمائندگی کرتا تھا۔ برہان الدین ربانی کی جماعت اسلامی نے 1993 میں مجاہدین حکومت کے لیے ایک آئینی مسودہ پیش کیا، لیکن دیگر جماعتوں نے اس پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے متبادل آئین تیار کرنے کی کوشش کی۔
شیعہ جماعت حزب وحدت نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا آئینی خاکہ تجویز کیا جو کثیرالمذاہب اور جامع وفاقی اسلامی ریاست کا تصور پیش کرتا تھا، تاکہ تمام گروہوں کو ایک متوازن کردار دیا جا سکے۔ اسی دوران حرکتِ اسلامی نامی تنظیم نے 1980 کی دہائی میں اپنا آئینی مسودہ تیار کیا تھا اور امید کی جا رہی تھی کہ اسے مجاہدین کی حکومت کے آئین میں شامل کیا جائے گا۔ ان تمام کوششوں نے واضح کیا کہ افغان جہاد کے بعد کے سیاسی منظرنامے میں اتحاد قائم رکھنا کتنا مشکل اور پیچیدہ کام تھا۔
سنی سیاسی جماعتوں کی تشکیل اور آئین کی تیاری
1970 کی دہائی میں اسلام پسند حلقے سیاست سے زیادہ تر دور رہے، لیکن اس دوران وہ اس بات پر تشویش میں مبتلا تھے کہ ان کے مخالف، کمیونسٹ، کس حد تک ریاستی اداروں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے تھے۔ 1973 تک افغان کمیونسٹ پارٹی (PDPA) اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اس نے محمد داؤد خان کے ساتھ مل کر ایک انقلاب کے ذریعے بادشاہت کا خاتمہ کیا۔ داؤد خان ایک سیکولر نظریات رکھنے والے شخص تھے جنہیں کمیونسٹوں کی حمایت حاصل تھی اور وہ اسلام پسندوں کے سخت مخالف تھے۔
داؤد کی حکومت (1978-1973) کے دوران کمیونسٹوں کو اہم حکومتی عہدوں پر فائز کیا گیا اور اسلام پسند تحریک کو سختی سے کچلنے کی کوشش کی گئی۔ اس دوران کئی اہم اسلام پسند رہنما، جیسے برہان الدین ربانی، گلبدین حکمت یار، عبدالرب رسول سیاف، اور صبغت اللہ مجددی، پاکستان کے شہر پشاور ہجرت کر گئے۔ وہاں انہیں پاکستانی حلقوں کی جانب سے بھرپور حمایت ملی، جنہوں نے انہیں بنیادی عسکری تربیت، مالی معاونت، اور ہتھیار فراہم کیے۔ پاکستان نے ان رہنماؤں کو افغان حکومت کے خلاف منظم مزاحمت شروع کرنے کی دعوت دی۔
ان جلا وطن اسلام پسندوں میں سے کچھ اس منصوبے کو فوراً شروع کرنے کے حامی تھے، جبکہ کچھ نے احتیاط برتنے کا راستہ چنا۔ ان اختلافات کی وجہ سے گلبدین حکمت یار نے برہان الدین ربانی سے علیحدگی اختیار کر کے ایک شدت پسند تنظیم، حزب اسلامی افغانستان، کی قیادت سنبھالی اور فوری طور پر عسکری کارروائیاں شروع کر دیں۔ دوسری طرف ربانی نے کئی سینئر اسلام پسند رہنماؤں کو اپنے ساتھ رکھا اور ایک بڑی جماعت، جمعیت اسلامی، کی قیادت جاری رکھی، جس نے حکمت عملی کے تحت انتظار کی پالیسی اپنائی۔
جب پاکستان میں سنی اسلام پسند اپنی تنظیم سازی میں مصروف تھے، افغان کمیونسٹوں نے حکومت میں اپنا کنٹرول مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ 1973 کے انقلاب میں داؤد خان کا ساتھ دینے کے بعد افغان کمیونسٹ پارٹ(PDPA) پردے کے پیچھے رہنے پر اکتفا نہیں کر رہی تھی۔ 1978 میں، انہوں نے ایک خونریز انقلاب کے ذریعے داؤد خان کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ لیکن کمیونسٹ حکومت اس بات کا ادراک نہ کر سکی کہ اسے نہ تو عوامی حمایت حاصل ہے، نہ ہی انتظامی صلاحیت، اور نہ ہی قانونی جواز اس کے پاس ہے۔
افغان کمیونسٹ پارٹ(PDPA)نے ایک غیر دانشمندانہ مارکسسٹ لیننسٹ سماجی اور سیاسی پروگرام نافذ کرنے کی کوشش کی، جو اقتصادی اور سماجی اصلاحات پر مبنی تھا۔ یہ پروگرام افغان عوام کے لیے ناقابلِ فہم اور ان کی اکثریت کے لیے ناقابلِ قبول ثابت ہوا۔ 1979 میں جب دیہی علاقوں میں بغاوتیں شروع ہوئیں تو سوویت یونین نے افغان کمیونسٹ پارٹ(PDPA)حکومت کو بچانے کے لیے افغانستان پر حملہ کر دیا۔
سوویت حملے کے بعد اسلام پسند جماعتوں کی تشکیل
سوویت یونین کے حملے کے نتیجے میں امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان سمیت کئی ممالک نے افغان اسلام پسندوں کو بھاری مالی امداد اور ہتھیار فراہم کیے۔ ان اسلام پسندوں نے کابل کی حکومت اور اس کے سوویت حمایتیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ جیسے ہی ان کی عسکری کامیابیاں بڑھنے لگیں، سنی اسلام پسند تحریک مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، جو اجتماعی طور پر سنی مجاہدین کہلانے لگے۔ ان جماعتوں میں یہ گروہ شامل تھے:
- جمعیت اسلامی، جس کی قیادت برہان الدین ربانی نے کی۔
- حزب اسلامی، گلبدین حکمت یار کی سربراہی میں۔
- اتحاد اسلامی، عبدالرب رسول سیاف کی قیادت میں قائم ہوئی۔
- حرکت انقلاب اسلامی، محمد نبی محمدی کی قیادت میں۔
- محاذ ملی اسلامی، سید احمد گیلانی کی سربراہی میں۔
- جبھه نجات ملی اسلامی، صبغت اللہ مجددی کی قیادت میں۔
ان جماعتوں کو ایک طرف تو کمیونسٹ حکومت اور سوویت افواج کی مخالفت نے متحد رکھا، اور دوسری طرف ایک اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش نے۔ لیکن ان کے درمیان مستقبل کے افغانستان کی شکل و صورت پر کوئی اتفاق رائے نہ ہو سکا۔
1989 میں جب سوویت افواج افغانستان سے نکل گئیں اور کمیونسٹ حکومت کے خاتمے کا امکان ظاہر ہونے لگا، تو ان جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان اقتدار کے حصول کے لیے رسہ کشی شروع ہو گئی۔ ہر رہنما اپنے مطلوبہ نظریات کے مطابق اگلی ریاست کی تشکیل کا خواہاں تھا۔
سنی مجاہدین نہ صرف آپس میں بلکہ شیعہ ملیشیا کے اتحادیوں کے ساتھ بھی اختلافات میں الجھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے کابل میں موجود کمیونسٹ حکومت کچھ عرصے تک خود کوبرقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔ بالآخر، 1992 میں، سنی مجاہدین رہنماؤں نے کابل پر قبضہ کر لیا اور ایک عبوری حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔
ابتدائی معاہدے کے مطابق، عبوری حکومت کی سربراہی دو ماہ کے لیے صبغت اللہ مجددی اور چار ماہ کے لیے برہان الدین ربانی کو سونپی گئی۔ اس دوران، اصل طاقت ایک 50 رکنی شوریٰ (شورائے رہبری) کے پاس تھی، جس میں تمام مجاہدین جماعتوں کے نمائندے شامل تھے۔ اس شوریٰ کا ایک اہم کام مستقل حکومت کے لیے منصوبے تیار کرنا تھا۔
مجاہدین جماعتوں کی حکومت، اندرونی کشیدگی، اور آئین سازی کا عمل
مجاہدین جماعتیں حکومت چلانے میں نہایت ناکام ثابت ہوئیں۔ جب ربانی کی بطور سربراہ چار ماہ کی مدت ختم ہوئی، تو مجاہدین جماعتیں مستقل حکومت کے ڈھانچے پر متفق نہ ہو سکیں۔ لیکن ربانی نے بھی اقتدار سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ فیصلہ اتحاد میں شامل دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کے لیے ناقابل قبول تھا اور بالآخر ایک خونی خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ اس لڑائی میں ہزاروں شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
مارچ 1993 میں بڑی سنی مجاہدین جماعتوں نے ایک نئے معاہدے پر اتفاق کیا، جس کے تحت ربانی کی بطور صدر مدت میں توسیع کی گئی لیکن گلبدین حکمت یار کو وزیراعظم کے طور پر اضافی اختیارات دیے گئے۔ اس مشترکہ حکومت کے تحت، مجاہدین جماعتوں کو آٹھ ماہ کا وقت دیا گیا کہ وہ تمام دھڑوں کے لیے قابل قبول آئین تیار کریں۔
یہ معاہدہ کابل میں نسبتاً امن کا باعث بنا، لیکن ربانی کے مخالفین، خاص طور پر حکمت یار، ان پر اور ان کی جماعت جمعیت پر کبھی اعتماد نہ کر سکے۔ حکمت یار نے بطور وزیراعظم کابل جانے سے انکار کر دیا اور اپنی حلیف سنی جماعتوں کے ساتھ اپنے مضبوط گڑھ میں کابینہ تشکیل دی اور اجلاس منعقد کیے۔ یوں ایک متوازی حکومت کا نظام وجود میں آیا، جو ربانی کی جگہ لینے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔
1993 کے وسط میں، ربانی کی جمعیت اور حکمت یار کی حزب اسلامی (اور اس کے حلیفوں) کے درمیان کشیدگی کھلی جنگ میں بدل گئی، جو پہلے کابل میں شروع ہوئی اور پھر ملک کے دیگر حصوں تک پھیل گئی۔
اس کشیدہ ماحول میں ربانی نے دیگر مجاہدین جماعتوں کے ساتھ مل کر جامع آئین سازی کا کمیشن قائم کرنے کی ذمہ داری ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بجائے، انہوں نے 44 اراکین پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا، جس میں نہ تو حزب اسلامی کے نمائندے شامل تھے اور نہ ہی طاقتور شیعہ دھڑوں کے۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسا آئینی مسودہ تیار ہوا، جس میں صدر کو مضبوط اور وزیراعظم کو نسبتاً کمزور اختیار دیا گیا۔
آئین کا تنازع، اقتدار کی کشمکش، اور طالبان کا ظہور
حکمت یار نے توقع کے مطابق آئینی کمیشن کے مسودے کو مسترد کر دیا، ان کا موقف تھا کہ اس آئین کے تحت صدر کی جماعت، یعنی جمعیت، تمام حکومتی فیصلوں پر حاوی ہو جائے گی۔ حکمت یار نے تجویز دی کہ وزیراعظم کے اختیارات کو بڑھایا جائے، لیکن جمعیت نے ان ترامیم کو رد کر دیا۔ ان کا مؤقف تھا کہ مجوزہ نیم صدارتی نظام کے تحت وزیراعظم کی جماعت (جو اس وقت حزب اسلامی تھی) حکومت پر غالب آ جائے گی۔
چھوٹی مجاہدین جماعتوں، بشمول چند شیعہ جماعتوں، نے تجویز دی کہ انتظامی اختیارات نہ صدر کے پاس ہوں اور نہ وزیراعظم کے، بلکہ یہ اختیارات تمام بڑی مجاہدین جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک گورننگ کونسل کو دیے جائیں۔ تاہم، نہ ربانی کی جمعیت اور نہ حکمت یار کی حزب اسلامی اس حل کو اپنانے پر تیار ہوئیں۔ دونوں جماعتیں اس طاقت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھیں جو وہ صدارتی یا نیم صدارتی نظام میں حاصل کر سکتی تھیں۔ مزید یہ کہ ان دونوں سنی جماعتوں نے شیعہ دھڑوں کو حکومت میں کوئی نمایاں کردار دینے سے بھی گریز کیا۔
آئین کے مسودے پر اتفاق نہ ہونے کے باعث جمعیت کی قیادت میں قائم اتحاد، حزب اسلامی کے اتحاد، اور شیعہ جماعتوں کے درمیان تنازعات شدت اختیار کر گئے، اور ہر جماعت اپنے اپنے مضبوط گڑھ میں واپس جا کر ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں مصروف ہو گئی۔ 1995 تک افغانستان مکمل طور پر انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔
اسی دوران ایک نئی اسلامی تحریک، طالبان، منظر عام پر آئی۔ یہ تحریک ان طلبہ پر مشتمل تھی جو دیہی علاقوں کے مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ طالبان مجاہدین جماعتوں کے خود غرض رویے سے سخت نالاں تھے۔ طالبان نے اتنی عسکری تربیت حاصل کر لی کہ وہ تیزی سے ملک کے بیشتر حصوں پر قابض ہو گئے۔
شیعہ اسلامی آئین
1970 کی دہائی کے اواخر میں، جب پاکستان میں موجود سنی مجاہدین جماعتیں کابل کی کمیونسٹ حکومت کے خلاف اپنی مسلح مزاحمت تیار کر رہی تھیں، تو ہزارہ جات کے علاقے میں شیعہ بھی کمیونسٹ حکومت کے خلاف اپنی مزاحمت کو منظم کر رہے تھے۔ 1979 کے موسم خزاں میں، کمیونسٹ انقلاب کے ایک سال سے بھی کم عرصے بعد، شیعہ رہنماؤں نے ایک سیاسی تنظیم قائم کی جس کا مقصد ہزارہ جات کو خود مختار علاقہ بنانا تھا۔
اس مقصد کے تحت افغانستان کی شیعہ قیادت نے شوریٰ اتحاد اسلامی افغانستان کے نام سے ایک تنظیم تشکیل دی۔ اس شوریٰ نے حکومت کے تمام عہدیداروں اور فورسز کو ہزارہ جات سے نکال باہر کیا اور اس کے بدلے ایک "چھوٹی ریاست” قائم کی۔ یہ ریاست اپنے شہریوں کو تعلیم، مواصلات، اور صحت کی سہولیات فراہم کرتی تھی؛ ٹیکس عائد کرتی؛ شناختی کارڈ تقسیم کرتی؛ اور فوجی خدمات کو لازمی قرار دیتی۔
افغان حکومت کی واضح طور پر سوویت یونین کے ساتھ شراکت داری اور معاشی و سماجی اصلاحات سے خائف ہو کر، متعدد شیعہ علما نے شوریٰ کی حمایت کی۔ ان علما میں معروف شیعہ رہنما سید علی بہشتی بھی شامل تھے، جو عراق کے ایک شیعہ مدرسے میں تعلیم حاصل کر چکے تھے اور شوریٰ کے سربراہ کے طور پر مقرر کیے گئے۔
بہشتی کا شوریٰ میں قیادت قبول کرنے کا فیصلہ ایک حیرت انگیز امر تھا۔ شیعہ "خوئی نظریے” کے مطابق، عام حالات میں علما کو عوامی سیاسی سرگرمیوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور خود کو اسلامی تعلیم و تبلیغ تک محدود رکھنا چاہیے۔ بہشتی اور ان جیسے دیگر طلبہ کا خیال تھا کہ علما کو مسلم عوام کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ اگر ریاست غیر منظم شیعہ قوانین کو بعض معاملات میں نافذ کرنے کا فیصلہ کرے، تو علما جج یا مشیر کے طور پر خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ریاست کسی مجوزہ قانون کو شیعہ اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنا چاہے، تو علما سے رائے لے سکتی ہے۔
تاہم، ان معاملات میں جہاں خدا کی مرضی کے تعین پر اختلاف ہو سکتا ہے، "خوئی نظریے” کے مطابق ان فیصلوں اور قوانین کے تعین کا اختیار سیکولر قیادت کو ہونا چاہیے۔
بہشتی کا سیاسی کردار اور خمینی فکر کے ساتھ تنازع
سید علی بہشتی، ایک "خوئی نظریے” کے پیروکار ہونے کے ناطے، صرف غیر معمولی حالات کی بنا پر تدریس اور مشاورت کے کردار سے سیاست میں قدم رکھنے پر آمادہ ہوئے۔ ان کے نزدیک، کمیونسٹ انقلاب اور سوویت افواج کی مسلم علاقوں پر یلغار نے ایک غیر معمولی خطرناک سماجی و سیاسی بحران کو جنم دیا تھا، جو شیعہ معاشرے کے لیے انتہائی مہلک تھا۔ ایسے حالات میں علما کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سیاسی کردار سے اجتناب کے اصول کو وقتی طور پر ترک کریں اور معاشرے کے دفاع کے لیے وہ سب کچھ کریں جو ان کے بس میں ہو، چاہے اس کا مطلب سیاسی قیادت کا منصب قبول کرنا ہی کیوں نہ ہو۔
بہشتی کی قیادت میں، شوریٰ کے رہنماؤں نے اپنی تمام تر توجہ ہزارہ جات کے آزاد شدہ علاقوں کے دفاع اور کنٹرول کو یقینی بنانے پر مرکوز کی، تا کہ ملک میں ایک "اسلامی جمہوریہ” کے قیام کا خواب پورا ہو سکے۔ اس دوران بہشتی اور دیگر خوئی نظریے کے علما نے یہ موقف اپنایا کہ یہ صرف ایک ہنگامی اقدام ہے۔ جیسے ہی حالات معمول پر آئیں گے، علما سیاست سے الگ ہو کر اپنی روایتی ذمہ داریوں کی طرف لوٹ جائیں گے۔
تاہم، وقت کے ساتھ شوریٰ کی محتاط پالیسی اور محدود سیاسی عزائم نے خمینی فکر کے ماننے والے انقلابی علما کو مایوس کیا۔ خمینی کے حامی علما کا اصرار تھا کہ شیعہ فقہا کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ فعال طور پر ایک اسلامی ریاست قائم کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام شہری خدا کے قانون کے تحت زندگی بسر کریں۔
اس اختلاف نے شیعہ معاشرے میں اندرونی تنازع کو جنم دیا۔ 1980 کی دہائی کے آغاز میں، جب اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی "اسلامی انقلاب” کی فکر کو دیگر شیعہ علاقوں تک پھیلانا شروع کیا، تو ہزارہ جات میں خمینی کے حامیوں نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ انہوں نے شوریٰ کو چیلنج کرنے کے لیے متعدد اہم سیاسی تنظیمیں قائم کیں۔ ایران میں مقیم افغان شیعہ یا وہ طلبہ جو وہاں تعلیم کے لیے گئے تھے، بڑی تعداد میں ہزارہ جات میں واپس آنے لگے۔
1980 کی دہائی کے وسط تک، خمینی کے حامی اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ انہوں نے شوریٰ کو بے دخل کر دیا اور شیعہ داخلی سیاست پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس طرح، ہزارہ جات میں خمینی نظریے کا غلبہ ہوا، جو شوریٰ کے ابتدائی نظریے سے واضح انحراف تھا۔
حرکت اسلامی: خوئی فکر کی بازیابی اور خمینی اثر کے خلاف جدوجہد
شوریٰ کے زوال کے باوجود، افغانستان میں خوئی نظریے کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا۔ 1980 کی دہائی کے اوائل میں، شیعہ سیاسی جماعتوں میں سے ایک نمایاں جماعت "حزب حرکت اسلامی” تھی، جو 1979 میں ایران کے شہر قم میں شیخ آصف محسنی کی قیادت میں تشکیل دی گئی۔ محسنی بھی خوئی کے شاگرد تھے اور ان کے خیالات کو حرکت کے اندر فروغ دینے میں پیش پیش رہے۔ جماعت کے بنیادی چارٹر میں اعلان کیا گیا تھا کہ اس کا اولین مقصد "قرآن، سنت، حکمت، اور فکری اصولوں پر مبنی ایک منصفانہ اسلامی جمہوریہ کا قیام” ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، افغانستان کے مسلمانوں کو کمیونسٹ حکومت اور غیر ملکی جارحیت سے آزاد کرانا بھی اس کے اہداف میں شامل تھا۔
تاہم، خوئی نظریے کے ماننے والوں کے لیے "اسلام کی بحالی” کا مطلب خمینی نظریے سے بالکل مختلف تھا۔ شوریٰ کی طرح، حرکت اسلامی کے چارٹر میں بھی اس بات کا اشارہ موجود تھا کہ قبضہ شدہ علاقوں کو ایک اسلامی جمہوریہ کے قیام کے بعد منتخب سیاسی قیادت کے حوالے کر دینا چاہیے، اور علما کو اپنے روایتی کاموں یعنی تعلیم و تبلیغ تک محدود رہنا چاہیے۔
خمینی کی حامی جماعتوں کے مسلسل دباؤ کے باعث، محسنی کی حرکت اسلامی نے پاکستان کا رخ کیا اور اپنا مرکز کوئٹہ میں قائم کیا۔ یہاں سے محسنی نے پاکستان اور پشاور میں مقیم سنی مجاہدین کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا۔ اس نئی قربت اور اتحاد نے حرکت کو افغان شیعہ سیاست میں ایران نواز اسلام پسندوں کی کامیابی کے باوجود متحرک رہنے کا موقع فراہم کیا۔
حزب حرکت اسلامی ایک قومی شیعہ جماعت تھی جو ایک کثیر المسلکی اور وحدانی اسلامی ریاست کا تصور پیش کر رہی تھی، جس میں سنی اور شیعہ علما کا کردار صرف ایک مشاورتی کونسل کے ذریعے نگرانی تک محدود تھا۔ یہ کونسل ان مسائل کی نشاندہی کرتی جہاں تمام مسالک میں اسلامی قانون کے حوالے سے اتفاق رائے موجود ہو۔ ہر مسلک کے علما کونسل میں ان امور کو واضح کرتے جو ان کے فقہی نظریے کے مطابق واجب العمل ہوں۔ جہاں قانونی معاملات پر اختلاف موجود ہو، وہاں حرکت کے آئین نے سیاستدانوں کو، جو عموماً فقہی تربیت سے محروم ہوتے، یہ اختیار دیا کہ وہ عوامی مفاد میں بہترین قانون سازی کریں۔
مختصر یہ کہ حرکت اسلامی کا آئین ایران کے خمینی ماڈل کا ایک خوئی نظرئیے پر مبنی متبادل پیش کرتا تھا۔ خمینی کے برعکس، یہ ماڈل علما کو صرف مشاورتی اور نگرانی کے کردار تک محدود رکھتا تھا، نہ کہ انہیں ایک سپریم لیڈر کے طور پر تمام ریاستی اختیارات کا حامل بناتا، جو یکطرفہ طور پر اسلامی قانون کے غیر طے شدہ معاملات میں فیصلہ کن کردار ادا کرے۔
افغان مجاہدین کےآئین کا مقدمہ
تحریکِ اسلامی افغانستان کی علمی کونسل کی ایک کمیٹی نے افغانستان کے لیے 1990میں ایک آئینی مسودہ تیار کیا تھا۔ اس آئین کے مقدمے سے چند اہم نکات قارئین کی توجہ کے مستحق ہیں:
۱۔ جعفری مکتب فکر کی آئینی حیثیت
اس مسودے میں جعفری مکتب فکر کو تسلیم کیا گیا ہے، جو شاید کچھ سنی بھائیوں کے لیے حیرت یا اعتراض کا باعث بنے۔ لیکن ہمیں جذبات کے بجائے حقیقت کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ افغانستان میں لاکھوں لوگ جعفری مکتب فکر سے وابستہ ہیں۔ اگر ان کی شناخت اور حقوق کو آئین میں شامل نہ کیا گیا تو ان کے لیے یہ آئین بے معنی ہوگا۔
افغانستان کے ماضی کے تناظر میں جعفری برادری کو کوئی تحفظ حاصل نہیں تھا۔ یہ رویہ جعفری مسلمانوں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزی تھا۔ چونکہ جعفری برادری اپنے مذہبی رسومات کے مطابق زندگی گزارتی ہے، اس لیے ان کے حقوق کو تسلیم کرنا آئینی انصاف کا تقاضا ہے۔
۲۔ اسلامی اصولوں کی بالادستی
مسودے میں اسلامی اصولوں کو ریاست کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، جو افغانستان کی زمینی حقیقت اور عوام کی اکثریتی رائے کی عکاسی کرتا ہے۔ اسلام ہمارے قومی اتحاد کا مرکز ہے اور ایک ایسی طاقت ہے جو ملک کے مختلف طبقوں کو یکجا رکھ سکتی ہے۔
۳۔ آزادی کا فروغ
آزادی کو مسودے میں ایک بنیادی حق کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ نہ صرف ہر انسان کا فطری حق ہے بلکہ افغانستان میں آمریت کو روکنے اور ایک متوازن سیاسی نظام قائم کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ آزادی ہماری قوم کی ترقی اور خودمختاری کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔
۴۔ سیاسی جماعتوں کی تعداد محدود نہ کرنا
اس مسودے میں افغانستان میں سیاسی جماعتوں کی تعداد کو محدود نہیں کیا گیا، لیکن ملک کے ماضی کے تجربات (خصوصاً 1973 کے انقلاب کے بعد) یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی بڑی تعداد نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر صرف تین جماعتوں کو کام کرنے کا حق دیا جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ ان میں سے دو جماعتیں سنی اور ایک شیعہ سیاسی جماعت ہونی چاہیے۔
۵۔ صدر اور قومی اسمبلی کے ارکان کے لیے استثنیٰ ختم
اس مسودے میں صدر اور قومی اسمبلی کے ارکان کو قانونی استثنیٰ فراہم نہیں کیا گیا ہے۔ اسلامی عدل کے اصولوں کے مطابق کسی بھی ریاستی عہدیدار کو ایسا استثنیٰ دینا غلط ہے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہییں۔ کسی کے عمل یا بات کا اگر قانون سے تضاد ہو تو اس پر وہی اصول لاگو ہونے چاہییں جو عوام پر لاگو ہوتے ہیں۔ عوام اور ان کے نمائندوں کے درمیان فرق یا امتیاز کرنا اسلامی اور اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے۔
۶۔ مجلس تدوین کے قیام کی تجویز
اس مسودے میں ایک "مجلس تدوین” کے قیام کی تجویز دی گئی ہے، جو اسلامی فقہ کے اصولوں کی تشریح اور قانون سازی میں معاون ہوگی۔ بظاہر یہ تجویز نئی اور حیرت انگیز معلوم ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ عوام اپنے نمائندوں کو علم، تجربے اور تقویٰ کی بنیاد پر منتخب نہیں کرتے، بلکہ سماجی تعلقات اور نسلی بنیادوں پر انتخاب ہوتا ہے۔ ان حالات میں زیادہ تر نمائندے مطلوبہ مذہبی علم اور اہلیت سے محروم ہوتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ملک کی اکثریت ناخواندہ ہے، اس مسئلے کا فوری حل ممکن نہیں۔ اس لیے اسلامی قانون کے معاملات کو سلجھانے اور قانون سازی میں مدد کے لیے مجلس تدوین ناگزیر ہے۔
۷۔ صدر کی مدت کی تحدید
مسودے میں صدر کے لیے ایک مدت کی حد مقرر کی گئی ہے تاکہ صدر جمہوری نظام پر غیر قانونی طور پہ اثرانداز نہ ہو سکے اور جمہوریت کو نقصان نہ پہنچائے۔
۸۔ صدر اور وزیر اعظم کا انتخاب
مسودے میں لکھا گیا ہے کہ صدر عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوگا جبکہ وزیر اعظم قومی اسمبلی کے ووٹ سے۔ یہ ایک بہتر تجویز ہے، لیکن ہم اس پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں عہدے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوں یا دونوں قومی اسمبلی کے ووٹ سے منتخب کیے جائیں۔
۹۔ وزراء کے تقرر اور برطرفی کے اختیارکا خاتمہ
اس مسودے میں صدر کو وزیر اعظم اور دیگر وزراء کے تقرر یا برطرفی کا اختیار نہیں دیا گیا۔ یہ انتظامی اختیارات کو تقسیم کرنے اور کرپشن و آمریت کے خطرے کو کم کرنے کی کوشش ہے۔ تمام اختیارات ایک فرد کو دینا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
۱۰۔ صدر کے اختیارات میں کمی
مسودے میں صدر کے بعض اختیارات "مجلس تدوین” کو دیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد شریعت کے اصولوں کی پاسداری کو یقینی بنانا ہے، کیونکہ صدر ممکنہ طور پر اسلامی شریعت کے علم سے محروم ہو سکتا ہے۔
یہ تجاویز افغانستان کے آئندہ آئینی ڈھانچے کو مزید منصفانہ اور مستحکم بنانے کی کوشش ہیں، جو اسلامی اصولوں اور عوامی مفادات کی ترجمانی کرتی ہیں۔
۱۱۔ غیر ملکی مداخلت سے گریز پر زور
اس مسودے میں غیر ملکی مداخلت سے اجتناب پر زور دیا گیا ہے کیونکہ ایسی مداخلت ہمیشہ تقسیم، اختلاف اور عدم استحکام کا سبب بنتی ہے۔ افغانستان کی سالمیت اور اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملکی معاملات میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت نہ ہو۔
۱۲۔ آئینی مسودے کو سمجھنے کی دعوت
ہم قارئین کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ "افغانستان میں اسلامی طرز حکومت کی تصویر” نامی کتاب کا مطالعہ کریں۔ یہ کتاب اس آئینی مسودے کو بہتر طور پر سمجھنے میں مددگار ہوگی۔
اختتامی بات
ہم ماہرین اور عوام کی رائے کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم خوشی محسوس کریں گے اگر اس مسودے کے حوالے سے سوالات کیے جائیں۔ عوام کی تجاویز اور سفارشات ہمارے لیے بہت اہم ہیں، اور ہم ان کا خیرمقدم کرتے ہیں تاکہ اس مسودے کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔